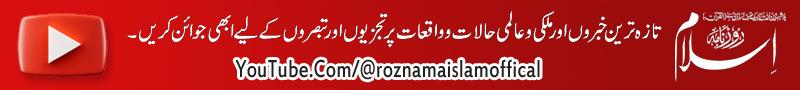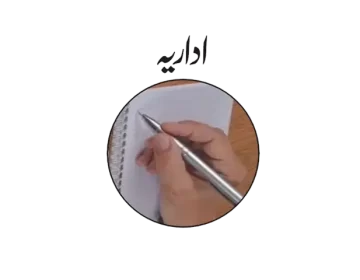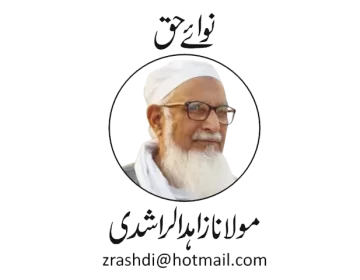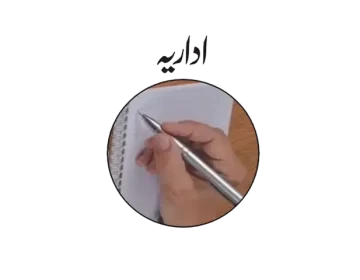دوسری قسط:
مندرجہ بالا اقتباس سے قارئین بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انگریزی سے عربی زبان میں ترجمہ کرنے کی مصنوعی ذہانت کی موجودہ صلاحیت کو فی الحال اکابرینِ امت اور ماہرینِ فن نے قبول نہیں کیا۔ کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے کہ شاید ان حضرات نے مصنوعی ذہانت کے عمدہ پیسوں والے سافٹ وئیر استعمال نہ کیے ہوں مگر ہم اپنے قارئین پر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے انگریزی سے عربی یا عربی سے انگریزی میں ترجمہ کا کام ابھی اتنا پائیدار اور بھروسہ کے قابل نہیں ہے کہ اس پر مکمل اعتماد کیا جا سکے۔ اس بات کی تائید سائنسی تحقیقات سے بھی ہوتی ہیں۔ ہیلیون Heliyonسائنسی جریدے میں شائع ہونے والی ایک سائنسی تحقیق بعنوان ”آرٹیفیشل انٹیلی جنس اینڈ ہیومن ٹرانسلیشن” کے اندر مصنوعی ذہانت کے ذریعے قانونی متن کے ترجمہ میں ہونے والی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ قانونی متن کا ترجمہ کرتے وقت قانونی ترجمہ میں مہارت رکھنے والے ایک ماہر انسانی مترجم کو اس ترجمے کی درستی کے لیے استعمال کیا جائے۔
جب ہم عربی زبان کے ترجمہ میں ہونے والی پیشرفت دیکھتے ہیں تو عربی ترجمہ نگاری میں بلاشبہ بہت ترقی اور پیشرفت ہوئی ہے مگر اس کا معیار اور پیشرفت ویسی نہیں ہے جیسا کہ دوسری زبانوں میں ہوئی ہو اور اس کی کئی وجوہات ہیں جن کو بڑی تفصیل کے ساتھ کمپیوٹر سائنسدانوں نے اپنی سائنسی مقالہ جات میں ذکر کیا ہے۔
جب کوئی مصنوعی ذہانت سے ترجمہ کروائے تو اسے بخوبی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کن مواقع پر مصنوعی ذہانت کو ترجمہ کرنے کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس ترجمہ کروانے کی کتنی حدود وقیود ہیں، مثلاً اگر عمومی طور پر ترجمہ کروانا ہو اور ایسی تحریر کا ترجمہ کروانا ہو جس کا دنیاوی کام پر اثر نہ پڑتا ہو تو بطور ایک مثال کے مصنوعی ذہانت کو استعمال کرکے ترجمہ کروا کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمومی طور پر اس تحریر میں کس موضوع پر بات کی گئی ہے مگر اس ترجمہ پر قطعی طور پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ نیز اگر کسی اہم دنیاوی دستاویز یا موضوع پر ترجمہ کروانا ہو تو مصنوعی ذہانت کے ترجمے پر فی الحال ہرگز ہرگز انحصار نہ کیا جائے کیونکہ ابھی مصنوعی ذہانت میں وہ صلاحیت نہیں آئی ہے کہ وہ سو فیصد صحیح ترجمہ کر سکے اور ترجمہ کرنے کا حق ادا کر سکے اور ایسی دعویٰ تو کسی مترجم کے ترجمہ پر بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر مترجم کا اسلوب بھی مختلف ہوتا ہے۔ نیز اگر کسی خاص تکنیکی و سائنسی موضوع پر ترجمہ کروانا ہو تو مصنوعی ذہانت پر فی الحال بھروسہ نہ کیا جائے کیونکہ اس تکنیکی و سائنسی موضوع کی اصطلاحات کو مصنوعی ذہانت صحیح طریقے سے ترجمہ نہ کر سکے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے کیا گیا ترجمہ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے مگر فی الحال اس میں کئی خامیاں ہوتی ہیں لہٰذا مصنوعی ذہانت کو بطور مترجم استعمال سے احتیاط برتی جائے۔
مصنوعی ذہانت سے ترجمہ کروانا اور پرائیویسی کے مسائل
مصنوعی ذہانت کے مروجہ سافٹ وئیر مثلاً چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے ترجمہ کروانے میں ایک پہلو پرائیویسی یعنی رازداری کا بھی ہے۔ اگر کوئی مصنوعی ذہانت کے سافٹ وئیر پر اپنا مواد ترجمہ کیلئے مہیا کرتا ہے تو اب اس مواد پر اس شخص کا کوئی کنٹرول نہیں رہا اور یہ مواد اب ان مصنوعی ذہانت کی کمپنیوں کی ملکیت بن گیا اور اس سے کاپی رائٹ وغیرہ جیسے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ کمپنیاں جیسے چاہیں آپ کے اس مواد کو استعمال کریں۔ دوم یہ کہ اگرآپ کسی اہم موضوع پر کام کر رہے ہیں تو ان سافٹ وئیر سے ترجمہ کروانے میں وہ ساری دستاویزات ان کمپنیوں کے پاس پہنچ رہی ہیں۔ سوم یہ کہ یورپی یونین و دیگر ممالک میں پرائیویسی پر قوانین موجود ہیں جو یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ عوام کو اپنا اہم مواد ان مصنوعی ذہانت کی کمپنیوں کو مہیا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چہارم یہ کہ اگر آپ کا کوئی سائنسی تحقیقی مقالہ ہے یا کوئی کتاب ہے جس کا ترجمہ کروا رہے ہیں تو جب آپ وہ مقالہ یا کتاب کسی سائنسی جریدے یا پبلشر کے پاس چھپنے کے لئے بھیجیں گے تو امکان ہے کہ آپ کے اس مواد کو سرقہ سمجھ کر واپس لوٹا دیا جائے اور آپ کے خلاف کارروائی ہو کیونکہ سائنسی جریدے یا پبلشر کو بعینہ وہی مواد کہیں اور بھی نظر آرہا ہوگا (جوکہ ممکنہ طور پر مصنوعی ذہانت کی ان کمپنیوں کے کمپیوٹرز پر یا کہیں اور موجود ہوگا جو کہ آپ ہی نے پہلے ان مصنوعی ذہانت کی کمپنیوں کو ترجمہ کیلئے مہیا کیا تھا) پنجم یہ کہ آپ کے مواد کو مصنوعی ذہانت کی کمپنیاں دوسری کمپنیوں کو اپنی مارکیٹنگ و دیگر استعمال کیلئے آپ سے پوچھے بغیر مہیا کر سکتی ہیں۔
مصنوعی ذہانت سے دینی علوم اور قرآنِ پاک کا ترجمہ کروانا
جہاں تک دینی علوم اور بالخصوص قرآنِ پاک کے ترجمہ کی بات ہے تو ان میں مصنوعی ذہانت کو قطعاً استعمال نہ کیا جائے بلکہ ایسا کرنے والوں کی سختی سے مذمت کی جانی چاہیے کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور ترجمہ قرآن ایک بہت اہم ذمہ داری کا کام ہے۔ قرآنِ پاک کے ترجمے تین طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک ”تحت اللفظ ترجمہ” یعنی لفظی ترجمہ، دوسرا ”سلیس ترجمہ” اور تیسرا ”بامحاورہ ترجمہ” (حوالہ: مولانا عمران عیسیٰ، وفاق المدارس العربیہ کے نصاب میں درجہ ثانیہ تا درجہ خامسہ ترجمہ قرآن اور تفسیر کیسے پڑھائیں؟ ماہنامہ بینات، اکتوبر 2023)
ان تینوں اقسام کے تراجم کے معنی تدریب المعلمین، اہدافِ تعلیم و اسلوبِ تدریس، وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں واضح انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔
”لفظی ترجمہ سے مراد یہ ہے کہ ہر لفظ کا ترجمہ اس کے ساتھ ہو۔ سلیس ترجمہ سے مراد یہ ہے کہ جملے کی ساخت اور ترکیب میں ترجمہ کی زبان کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ ترجمہ الگ الگ کلمات کی حد تک تو لفظی ہوتا ہے، مگر اس میں فعل، فاعل، مفعول، مضاف، مضاف الیہ، موصوف، صفت وغیرہ کی ترتیب میں اردو اسلوب کی پیروی کی جاتی ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سے مراد یہ ہے اس میں ترتیب کے لحاظ سے اردو کے اسلوب کی پیروی کی جاتی ہے نیز کلمات اور جملوں کا مفہوم ادا کرنے کے لیے اردو زبان کے محاورات اور ادبی کلمات کا انتخاب کر کے مزید تحسین کی کوشش کی جاتی ہے”۔
یہ تمام اقسامِ تراجم علمائے کرام کو مدارسِ دینیہ میں سکھائے جاتے ہیں اور اس کیلئے اکابرین کے تراجم پر ہی بھروسہ کیا جاتا ہے۔ یعنی ترجمہ قرآن میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی طالبِ علم اپنی فہم وفراست سے قرآنِ پاک کا محض لغت کی بنیاد پر ترجمہ کرلے بلکہ وہی ترجمہ قابلِ قبول ہوتا ہے جو کہ امت نے متفقہ طور پر قبول کیا ہو۔ (جاری ہے)