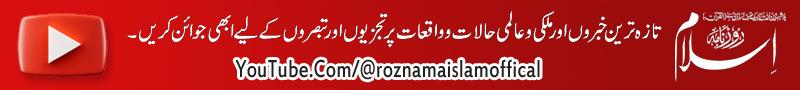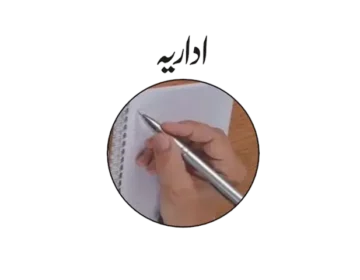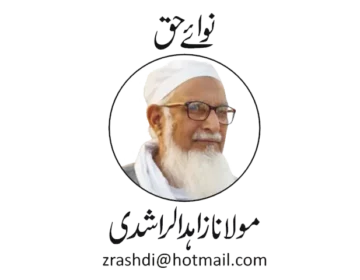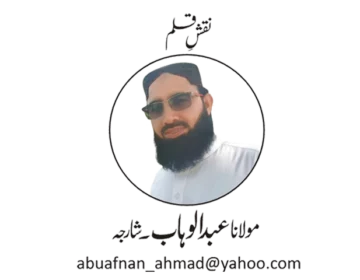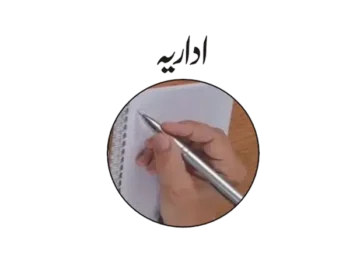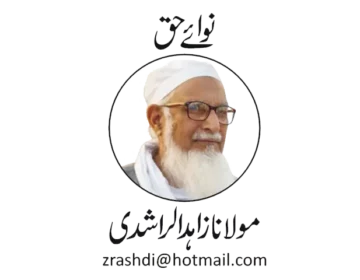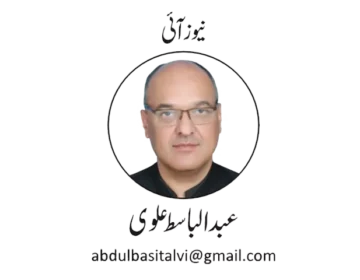تیسری اور آخری قسط:
کیا مصنوعی ذہانت کی مشین جوابدہ ہوگی؟
پھر یہ بھی سوال اٹھے گا کہ کیا مشین جوابدہ ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں! مشین جوابدہ نہیں ہو سکتی۔ مصنوعی ذہانت کے عالمی اور مستند سائنسی ماہرین مصنوعی ذہانت کی خامیاں اور کمزوریاں گنواتے نہیں تھکتے۔ مثلاً یونیورسٹی آف گلاسگو، برطانیہ کے ڈاکٹر جو سلیٹر یہ کہتے ہیں کہ: ”چیٹ جی پی ٹی خود سے مواد بنادیتا ہے جسے لوگ ہیلوسینیشن سے تعبیر کرتے ہیں جبکہ اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جو درست اصطلاح ہوگی وہ فضول، لغو یا بکواس کہا جائے اور اسے وہ ”فضول، لغو یا بکواس مشینوں” سے تعبیر کرتے ہیں”۔
ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا دین کے انتہائی اہم مسائل جن کے جواب پر عمل کرنے اور نہ کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کا مدار ہے (اور اس دنیاوی زندگی کا بھی مدار ہے مثلاً میراث میں غلط جواب دینے کی صورت میں کسی وارث کا حق محروم ہوسکتا ہے)، اس کے لیے ہم ایسی ”فضول، لغو یا بکواس مشینوں” پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہم اپنی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ نیز، آخرت میں ان مصنوعی ذہانت کی حامل مشینوں سے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بازپرس نہیں ہوگئی اور نہ ہی دنیاوی قوانین کے تحت یہ مصنوعی ذہانت کی مشینیں جوابدہ ہیں۔ پھر کیوں کچھ صاحبانِ علم عوام الناس کی غلط ذہن سازی کررہے ہیں کہ دینی مسائل کو مصنوعی ذہانت کے پروگرامز سے پوچھا جائے؟ پھر کیوں مدارسِ دینیہ کے طلبہ کرام کو چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرکے علمی استعداد بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے؟ ایسے صاحبانِ علم اور بہی خواہانِ امتِ مسلمہ سے مکرر عرض ہے کہ چونکہ آپ کو کمپیوٹر سائنس اور مصنوعی ذہانت کی پیچیدگیوں اور خامیوں کا علم نہیں اور نہ ہی آپ اس مشکل سائنسی موضوع کے ماہر ہیں لہٰذا مصنوعی ذہانت کے موضوع کے مستند عالمی ماہرین کی رائے پر کلی اعتماد کرتے ہوئے مصنوعی ذہانت کو مدارسِ دینیہ میں رواج دینے سے گریز کیجئے! نیز، مصنوعی ذہانت کے پروگرامز کو علومِ وحی کے سمجھنے، سیکھنے سکھانے اور ترویج و اشاعت کے لیے ہرگز ہرگز استعمال نہ کیا جائے بلکہ جو ”خیر القرون ” میں طریقہ کار اختیار کیے گئے ہیں یعنی ”سینہ بہ سینہ علوم کی منتقلی” اور ”سند”، انہی پر انحصار اور انہی کے ذریعے دینی علوم کو اگلی نسل تک منتقل کرنا چاہیے۔
مصنوعی ذہانت کے پروگرامز سے دینی علوم حاصل کرنا:
دیکھئے اگر کسی کے پاس عصری تعلیمی یونیورسٹیوں کی کلیہ الشریعہ یا کلیہ اصول الدین کی ڈگری ہو یا پھر مغربی ممالک کے لادینی عصری اداروں سے اسلامی دینی تعلیم کی ڈگری ہو تو ان دونوں طرز کے حامل ڈگری یافتہ لوگوں کا مدارسِ دینیہ سے فارغ التحصیل علماء کرام سے کیا بنیادی فرق ہے ؟ علمائے کرام اس کے کچھ بنیادی فرق بیان کرتے ہیں جن میں سب سے بڑا فرق ”سند”، اور ”سینہ بہ سینہ علوم کی منتقلی”، دوسرا اتباعِ سنت، تقویٰ، اخلاص، للہیت اور تربیت ظاہر و باطن اور تیسرا نصاب کا ہے۔ یہ وہ تین عناصر ہیں جوکہ بحیثیتِ مجموعی عصری تعلیمی یونیورسٹیوں کی کلیہ الشریعہ یا کلیہ اصول الدین یا پھر مغربی ممالک کے لادینی عصری اداروں سے اسلامی دینی تعلیم کی ڈگری حاصل کرنے والوں میں عنقا ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ غرض جب مصنوعی ذہانت کے پروگرامز سے دینی علوم حاصل کیے جائیں گے اور اپنی دینی و علمی استعداد بڑھانے کے لیے ان مصنوعی ذہانت کے پروگرامز کو استعمال کیا جائے گا تو اس سے ایک طرف سے ”سند” اور ”سینہ بہ سینہ علوم کی منتقلی” کی نفی ہو رہی ہے اور دوسری طرف چونکہ ان مصنوعی ذہانت کے پروگرامز میں سائنسی و تکنیکی خامیاں موجود ہیں، لہٰذا اس سے اصل دینی علوم بھی حاصل نہ ہوپائیں گے اور ایسے صاحبانِ علم اس دھوکہ میں ہی رہیں گے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کو سیکھ کر علمِ دین اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔
خلاصہ کلام یہ کہ راقم بطور کمپیوٹر سائنسدان اور محقق یہ بڑی ذمہ داری سے ساتھ عرض کرے گا کہ مصنوعی ذہانت کے پروگرامز کو علومِ وحی کے سمجھنے، سیکھنے سکھانے اور ترویج و اشاعت کے لیے ہرگز ہرگز استعمال نہ کیا جائے بلکہ جو ”خیر القرون” میں طریقہ کار اختیار کیے گئے ہیں یعنی ”سینہ بہ سینہ علوم کی منتقلی” اور ”سند”، انہی پر انحصار اور انہی کے ذریعے دینی علوم کو اگلی نسل تک منتقل کرنا چاہیے۔
اگر کوئی عامی شخص بخاری شریف کی ہر حدیث کو زبانی یاد کر لے اور پھر اس کا درس دینا شروع کر دے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ عالم نہیں ہے، اس کے پاس سند نہیں ہے اور اس کا بخاری شریف کا درس دینا معتبر نہیں ٹھہرے گا کیونکہ اس نے علمائے کرام اور شیوخ حدیث کی صحبت نہیں اٹھائی، ان سے علم حاصل نہیں کیا، اور اس نے سینہ بہ سینہ علم کی منتقلی حاصل نہیں کی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جتنے بھی فتنے پھیلتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ خود ہی دینی علوم کو پڑھ کر، سمجھ کر، عقل لڑا کر دینی علوم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ ایسے حضرات کو اکابر کا مزاج و مذاق، سلف کی رائے، صحابہ کرام کی رائے اور عمل کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا، نیز ان کو حدیث کا سیاق و سباق اور اس میں درج متن حدیث سے کیا مراد لی جائے گی، اس کی عملی تطبیق کیا ہوگی، کا بھی علم نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمرا ہ کرتے ہیں۔
خلاصہ مضمون یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس سے جڑی جدید ٹیکنالوجیز اور مصنوعی ذہانت کے بلاشبہ مثبت استعمال بھی ہیں اور ان سے انسانیت کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے مگر جہاں ایک طرف ان کے فوائد ہیں، وہیں اس ٹیکنالوجی کے منفی استعمال کے ساتھ ساتھ حدود و قیود بھی ہیں۔ اس سلسلے میں بندہ نے چند گزارشات پیش کی ہیں، ان کا خلاصہ درجِ ذیل ہیں۔
٭مدارسِ دینیہ کے طلبہ کرام میں پختہ علمی و تحقیقی استعداد بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کے سافٹ وئیر کے استعمال پر مدارسِ دینیہ میں سختی سے پابندی لگائی جائے۔ بالخصوص فقہی مسائل کی تحقیق، خلاصہ، تفسیر، احادیث کی تخریج، اور فتاویٰ نویسی کے لیے چیٹ جی پی ٹی و دیگر مصنوعی ذہانت کے سافٹ وئیر کو استعمال کرنے سے مکمل احتراز کیا جائے۔ راقم کی اس تجویز سے ہرگز یہ تاثر نہ لیا جائے کہ راقم مصنوعی ذہانت کو صرف مدارسِ دینیہ اور دینی علوم میں استعمال کرنے سے منع کر رہا ہے بلکہ حقیقتِ حال یہ ہے کہ دنیا کی بیشتر بہترین یونیورسٹیوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر پابندی عائد ہو چکی ہے جس کی تفصیل مع حوالہ جات راقم نے اپنے دوسرے مضمون میں مہیا کر دی ہے۔
٭مصنوعی ذہانت قطعی طور پر وحی کے علوم کا متبادل نہیں ہو سکتی لہٰذا سختی کے ساتھ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ مصنوعی ذہانت کو علومِ وحی کے متبادل کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔
٭مصنوعی ذہانت کے پروگرامز کو علومِ وحی کے سمجھنے، سیکھنے سکھانے اور ترویج و اشاعت کے لیے ہرگز ہرگز استعمال نہ کیا جائے بلکہ جو ”خیر القرون” میں طریقہ کار اختیار کیے گئے ہیں یعنی ”سینہ بہ سینہ علوم کی منتقلی” اور ”سند”، انہی پر انحصار اور انہی کے ذریعے دینی علوم کو اگلی نسل تک منتقل کرنا چاہیے۔