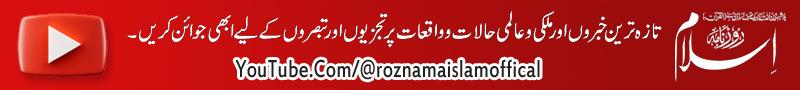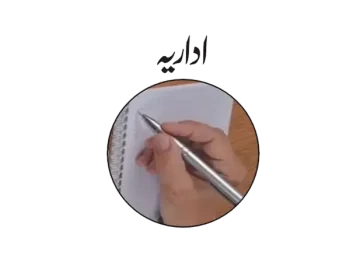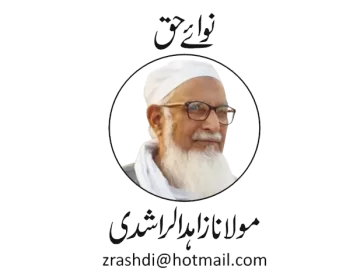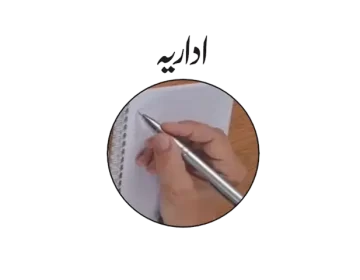دوسری قسط:
علامہ ابن اثیر جزری نے ”جامع الاصول” میں لکھا: ”علماء نے اس حدیث کی تاویل میں کلام کیا ہے اور ہر ایک نے اپنی فہم کے مطابق کسی نہ کسی عالم کو مجدِّد اور اس حدیث کا مصداق قرار دیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کو عام رکھا جائے، کیونکہ لفظِ ”مَنْ” کا اطلاق واحد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے۔
تجدید کا تعلق صرف فقہاء کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، اگرچہ دین کے معاملے میں امت کو زیادہ فائدہ علماء ہی سے پہنچا ہے۔ مجدِّد کسی عہد کا اولوالامر یا صاحبِ اقتدار بھی ہو سکتا ہے، جیسے عہدِ ملوکیت میں نظامِ حکومت کی اصلاح کے باعث حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مُجَدِّد تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہر شعبے کے لیے الگ الگ مجدِّد بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دین اور مسلمانوں کے نظمِ اجتماعی کی تدبیر اور عدل کا قیام صاحبانِ اقتدار کی ذمے داری ہے، علومِ دینیہ کے مختلف شعبوں کے غیر معمولی ماہر کو بھی اپنے شعبے کا مجدِّد قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان فنون میں مجدِّد اپنے عہد کے لوگوں میں ممتاز ہو اور اُس کے نمایاں تجدیدی کارنامے سب پر عیاں ہوں۔ تجدید ایک اضافی امر ہے، موجودہ دور میں دین سے انحراف، آزاد روی، دین سے بیزاری اور الحاد مائل بہ ترقی ہے، سومُجدِّد کا اپنے عہد کے لوگوں سے تقابل ہوگا نہ کہ قرنِ اول سے لے کر آخر تک، کیونکہ متقدمین عہدِ نبوت سے قُرب کے سبب علم، عمل، حِلم، فضل اور تحقیق وتدقیق میں یقینا متاخِّرین پر فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ جس کا دور مَنبعِ نورِ ہدایت سے جتنا قریب رہا، اُس پر نور کا فیضان اتنا ہی زائد رہا، (مرقاة المفاتیح، ج: 1ص: 322، خلاصۂ بحث)۔
ہر زمانے میں ایک ایسا تَجدُّد پسند طبقہ موجود رہا ہے جو خدمتِ دین کے نام پر دین کی نِت نئی تعبیرات وتشریحات پیش کرتا ہے، وہ ماضی کے مسلّمہ علمی وفقہی اُصولوں سے انحراف کرکے نئے خود ساختہ اصول وضع کرتا ہے اور اُمت میں اپنی فکری بدعات کو اِس انداز میں متعارف کراتا ہے کہ اس کا ایک پہلو دین سے بھی جڑا نظر آئے، لیکن ساتھ ہی وہ روایتی دین سے جدا بھی نظر آئے، یعنی دین کی ایسی تعبیر وتشریح کہ جس میں جدّت اور نیا پن بلکہ کسی حد تک انوکھا پن ہو۔ الغرض دین کے بارے میں ایسی وارداتیں کرنے والے خیرخواہ کے روپ میں وار کرتے ہیں۔ شیطان کا طریقہ بھی یہی رہا ہے، اُس نے حضرت آدم وحوا کو جب بہکانا چاہا تو قرآنِ کریم میں ہے: ”وہ قسمیں کھا کر آدم وحوا کو باورکراتا رہاکہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں، (الاعراف:21)”۔ پس دین میں بگاڑ پیدا کرنے والا یہ طبقہ بھی مُصلح اور خیر خواہ کے روپ میں نمودار ہوتا ہے۔ اس کی روح یہ ہے کہ دین کی وہ تعبیر وتشریح کی جائے جو مغرب کے لیے کسی درجے میں قابلِ قبول ہو، پس یہ روش مسلمانوں سے رسوخ فی العلم اور تَصَلُّبْ فِی الدِّیْن کی خوبی کو سلب کر کے دین کو لچکدار بنانے کا نام ہے کہ اُسے جدھر چاہیں، موڑ دیں اور جس تعبیر کا لِبادہ پہنانا چاہیں، پہنا دیں۔
اِس ڈَگر پر چلنے والی تجدُّد کی خواہ قدیم تحریکیں ہوں (جیسے خوارج اور مُعتزلہ) یا عصر حاضر کی جدید تحریکیں ہوں، ان کا پہلا نشانہ سنت وحدیث بنتی ہیں۔ پس سنت وحدیث ہی قرآنی فکر کو تفصیلی عملی ڈھانچہ فراہم کرتی ہیں اور دین کواپنی منشا کے مطابق ڈھالنے میں اِنحرافی واِلحادی تحریکوں کی راہ میں رُکاوٹ بنتی ہیں، لہٰذا قرآن اور دین کی من پسند تفسیر وتاویل اور اسے جدید افکار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ان متجدِّدِین حضرات کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ درمیان میں سے سنت وحدیث کا کانٹا نکال دیا جائے۔ یہ وہی مرض ہے جس کی تشخیص حضرت عمر بن خطاب نے ان الفاظ میںکی ہے: ”عقل پرست لوگ سنت کے دشمن ہوتے ہیں، وہ احادیث کو یاد نہیں رکھ سکتے اور ان احادیث کی فہم اور ان کا استحضار ان کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ پس جب صورتحال یہ ہو اور ان سے دین کے بارے میں سوالات کیے جائیں تو اُنہیں”میں نہیں جانتا”کہنے میں عار محسوس ہوتا ہے، لہٰذا یہ لوگ فہمِ دین میں سنت کی بجائے اپنی عقل کو ہی معیار بنالیتے ہیں۔ (جَامِعُ بَیان الْعِلْمِ وَفَضْلِہ: 2001)”متجدِّدین کا طبقہ مسلمانوں کے ردِّعمل سے بچنے کے لیے حدیث وسنّت کا مطلق انکار تو نہیں کرتا، لیکن حجّیتِ حدیث کی نفی کردیتا ہے، جب حُجّیتِ حدیث کی نفی کردی جائے تو آیاتِ قرآنی کی مَن مانی تاویلات وتوجیہات کرنے کا راستہ کھل جاتا ہے۔
حدیث پاک میں ہے: ”بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان سے علم کو یونہی نہیں اٹھا لیتا (کہ غبارے کی شکل میں اڑتا ہوا نظر آئے) بلکہ جب علمائے حق کو اٹھا لیا جاتا ہے تو اُن کے ساتھ علمِ حق بھی اٹھ جاتا ہے حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے تولوگ جاہلوں کو اپنا (دینی) سربراہ بنا لیتے ہیں، پھر جب اُن سے مسائل پوچھے جاتے ہیںتو وہ( اپنے جہل کا اعتراف کرنے کی بجائے) جہالت پر مبنی فتوے دیتے ہیں، پس وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، (بخاری: 100)”۔
برصغیر پاک وہند میں تجدّدی فکر کے علَم بردار سر سید احمد خاں تھے، چنانچہ اُنہوں نے اپنی ایک نئی دنیا بساتے ہوئے معجزات کا انکار کیا اور اَسلاف کی اِجماعی ومتفق علیہ تعبیرات سے ہٹ کر تعبیر پیش کی، جو اُن کے بقول عقل یا قوانینِ فطرت کے مطابق تھی۔ پھر یہ روایت جسٹس امیر علی، عبد اللہ چکڑالوی، علامہ عنایت اللہ مشرقی، اسلم جیراج پوری، چَراغ علی اور احمد دین امرتسری اور مولانا وحید الدین خان سے ہوتے ہوئے قیام پاکستان کے بعد غلام احمد پرویز، غلام جیلانی برق اور نیاز فتح پوری وغیرہ تک پہنچی۔ آج کل اس کے علم برداروں میں جناب جاوید احمد غامدی نمایاں ہیں۔
اُمت میں تجدُّد پسندی کے رجحان کو جواز فراہم کرنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں:کبھی دین کو نئے زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے نام پر، کبھی نئی نسل کے ذہنوں میں پائے جانے والے شبہات کے ازالے کے نام پر اور کبھی اسلام کے دفاع کے نام پر تجدُّد پسندی کی راہ اختیار کی جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقی دفاع تو یہ ہے کہ دین اور نصوصِ قرآن وحدیث کو عقل ونقل سے درست ثابت کیا جائے، جبکہ متجدِدین اصل دین سے ہٹ کر نصوصِ قرآن کی ایسی من پسند تعبیرات کرتے ہیں جو آزاد خیال لوگوں کے نزدیک قابلِ قبول ہوں، وہ متصلِّب وراسخ العقیدہ دین داروں کو غالب کے اس شعر کا مصداق قرار دیتے ہیں:
اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو
جو مے و نغمہ کو اندوہ ربا کہتے ہیں
مفہومی ترجمہ: ”یہ گزرے زمانے کے لوگ ہیں، ان سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو (خوشی کے اسباب) یعنی شراب وموسیقی کو بھی غم کے اسباب سمجھتے ہیں”۔
اِن متجدِّدِین حضرات کے لیے تجدُّد پسندی کے نام پر اپنے نت نئے افکار کو کسی طرح کی سندِ جواز فراہم کرناکسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ کتاب وسنت اور اُن سے استنباط واستدلال کاجو طریقہ علمائے اُمت کا امتیاز اور خاصّہ رہا ہے، اس سے ان تجدُّد پسندوں کو دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ قرآن وسنت کی استنادی حیثیت اور اُصولِ فقہ و اُصولِ حدیث جیسے علوم آلیہ سے عام طور پر انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ بلکہ ان میں سے اکثر کی عربی زبان سے واقفیت بھی عموماً واجبی سی ہوتی ہے۔ وہ اکثر خود ساختہ تخیُّلاتی پیمانوں کی مدد سے تفہیم دین کا فریضہ انجا م دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ حضرات اپنے اپنے افکار کو اسلامیانے اور ان پر دین کا رنگ چڑھانے کے لیے تجدیدِ دین کے سائبان میں پناہ حاصل کرتے ہیں۔ گویا تجدید کے اصل کلمے یا لفظ ِجدیدسے ان حضرات نے یہ معنی سمجھا ہے کہ ہر دور میں اسلام کی ایک نئی تعبیر اور تشریح ہوگی۔ الغرض تجدیدِ دین کا یہ مفہوم لینا غلط ہے کہ دین میں جد ت کی گنجائش موجود ہے، حالانکہ تجدُّد پسندی اپنی حقیقت اور اثرات کے اعتبار سے تجدید کی ضد ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے:
خود بدلتے نہیں، قرآں کو بدل دیتے ہیں
ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق
فکری بدعت اور دین کو باطل افکار اور خواہشات کے تابع بنانے کا نام تجدُّد ہے، جبکہ اصلِ دین کی طرف لوٹنے اور دین کو اپنی اصل شکل میں پیش کرنے اور فعّال بنانے کا نام تجدید ہے۔ (جاری ہے)