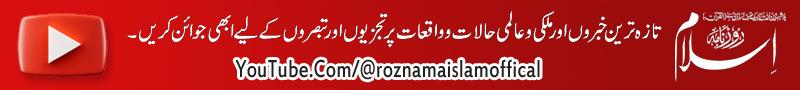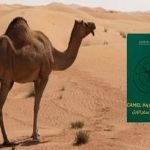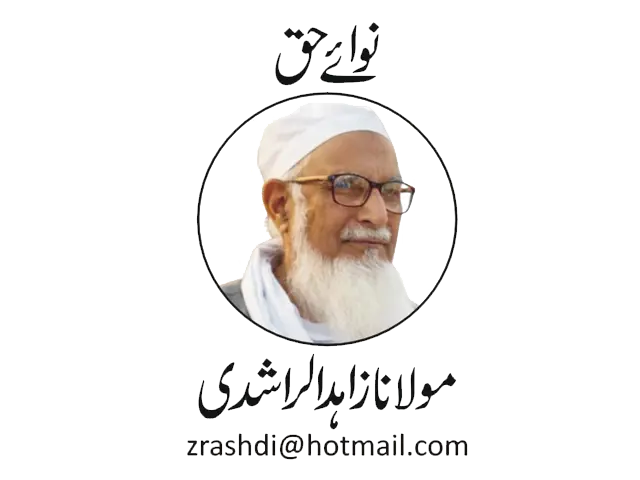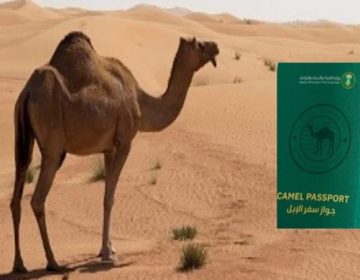جنوبی ایشیا میں مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ آنے والے دور کی ضرورت کا قبل از وقت اندازہ کرتے ہوئے انہوں نے اجتہاد کی جدید ضروریات اور تقاضوں پر علمی انداز میں بحث کی اور اپنے معروف خطبہ اجتہاد میں اہل علم کو ان ضروریات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بحث و تمحیص کا ایک عملی ایجنڈا بھی ان کے سامنے رکھ دیا۔ قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کے ایک طالب علم کے طور پر علامہ اقبال کے خطبہ اجتہاد کے بارے میں دوسرے بہت سے حضرات کی طرح میرے بھی بعض تحفظات ہیں، لیکن مجھے اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی حجاب نہیں ہے کہ تمام تر تحفظات کے باوجود اقبال کا یہ خطبہ اجتہاد آنے والے دور کی ضروریات اور تقاضوں کے پیش نظر اجتہاد پر بحث و مباحثہ کے لیے ایک قابل توجہ اور لائق غور علمی اور عملی ایجنڈا ہے، اسی لیے اس کے بعد سے اجتہاد کے جدید تقاضوں کے حوالہ سے جب بھی گفتگو ہوئی ہے، اسے کسی بھی مرحلہ میں نظر انداز نہیں کیا جا سکا۔ اس سے قبل سر سید احمد خان مرحوم نے بھی اس رخ پر کام کیا تھا مگر میری طالب علمانہ رائے میں سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کے کام میں ایک واضح فرق ہے جس نے دونوں کے نتائج کو مختلف بنا دیا ہے۔
سر سید احمد خان نے جس دور میں بات کی وہ 1857ء کے بعد ہمارے علمی اور معاشرتی ڈھانچوں کی ٹوٹ پھوٹ کا زمانہ تھا۔ اس وقت صرف اور صرف تحفظ ہی ہر صاحبِ فکر مسلمان کے ذہن میں تھا اور ہر طرف ایک ہی سوچ تھی کہ جو کچھ بچایا جا سکتا ہو، بچا لیا جائے۔ اس کے لیے روایتی علمی و دینی حلقوں نے اپنے انداز میں اور سر سید احمد خان نے اپنے انداز میں محنت کی۔ ظاہر بات ہے کہ تحفظات کے دور میں حساسیت بھی اسی حساب سے بڑھ جاتی ہے اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے سر سید احمد خان کے اصل کام کی بجائے ان کے تفردات زیادہ تر موضوع بحث بنے اور روایتی دینی حلقوں میں سر سید احمد خان کے اصل کام کو پذیرائی حاصل نہ ہو سکی جبکہ علامہ اقبال نے اس دور میں بات کی جب ہم غلامی کا ایک دور گزار کر آزادی کی طرف بڑھ رہے تھے، امید کی کرنیں روشن ہونے لگی تھیں اور بہتر مستقبل کے کچھ آثار دکھائی دینا شروع ہو گئے تھے، اس لیے علامہ اقبال کے تفردات کی بجائے ان کے کام کی مقصدیت کی طرف نظریں زیادہ اٹھنے لگیں اور جہاں ان کا ”خطبہ اجتہاد” جدید علمی حلقوں کی توجہات کا مرکز بنا، وہاں روایتی دینی حلقوں کے لیے بھی اسے یکسر نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ دینی حلقوں نے علامہ اقبال کے خطبہ اجتہاد کو من و عن قبول کر لیا، اس لیے کہ جب خود اس کے بارے میں اپنے تحفظات کا ذکر کر رہا ہوں تو یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس شدت کے ساتھ سر سید احمد خان کے تفردات کو مسترد کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس دور کا مخصوص ماحول تھا، علامہ اقبال کو اس طرح کے شدید ردعمل کا سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ میں آگے چل کر عرض کروں گا کہ خود روایتی دینی حلقوں نے اس کے بعد جب اجتہاد کی طرف عملی قدم بڑھایا تو علامہ اقبال کے بیان کردہ دائرے ہی ان کے کام آئے۔
اس تمہید کے ساتھ ”اقبال کا تصور اجتہاد” کے مرکزی عنوان کے سائے میں ”جدید سیاسی نظام اور اجتہاد” کے موضوع پر اس سیمینار میں ارباب علم و دانش کے سامنے کچھ طالب علمانہ گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔
جدید سیاسی نظام میں اجتہاد کے حوالہ سے گفتگو کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں کچھ عرض کروں، اس لیے کہ اس کا کوئی خاکہ سامنے رکھے بغیر جدید سیاسی نظام کے اجتہادی تقاضوں پر گفتگو کرنا ایک ایسی یکطرفہ بات ہوگی جس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکے گا۔ اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں میری طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے چند بنیادی اصول تو بیان کیے گئے ہیں، جن سے ایک اسلامی حکومت کے دائرہ کار اور حدود کا تعین ہو جاتا ہے، لیکن سیاسی نظام کا کوئی متعین ڈھانچہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ اسے امت کی صوابدید پر ہر دور کے حالات کے تناظر اور ضروریات کے لیے اوپن چھوڑ دیا گیا ہے جو بہت بڑی حکمت کی بات ہے۔ اس کا مطلب اس اہم کام کو نظر انداز کر دینا نہیں ہے بلکہ ایسا کر کے حالات کے اتار چڑھاؤ، نسل انسانی کے معاشرتی ارتقا، زمانہ کے تغیرات اور مختلف علاقوں اور زمانوں کے لوگوں کے مزاج و نفسیات میں پائے جانے والے فطری تنوع کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر قسم کے جائز امکانات کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے، جو مسلسل تغیر پذیر انسانی سوسائٹی کے فطری تقاضوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہے، البتہ بنیادی اصول اور حدود قرآن و سنت میں بیان کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی دور میں کوئی اسلامی حکومت ان بنیادی مقاصد اور دائرہ کار سے تجاوز نہ کرنے پائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورة المائدہ کی آیت 43سے آیت 50تک بنی اسرائیل کے سیاسی نظام کا ذکر کیا ہے اور اس کی حدود بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور نور ہے۔ انبیائے کرام، علماء کرام اور خدا پرست لوگ اس کے مطابق حکم کرتے تھے۔ پھر ہم نے انجیل نازل کی جو تورات کے احکام کی تصدیق کرنے والی ہے اور پھر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق حکم نہیں کرتے، وہ ظالم، فاسق اور کافر ہیں۔
اس کے ساتھ ہی ان آیات میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے کریں اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور یہ فرمان خداوندی بھی انہی آیات میں موجود ہے کہ لوگوں کی خواہشات کو فیصلوں کی بنیاد بنانا جاہلیت اور گمراہی کا ذریعہ ہے۔ پھر یہیں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ لوگوں کی خواہشات کی مطلقاً نفی نہیں ہے بلکہ ”ولا تتبع اھواء ھم عما جائکم من الحق” کا جملہ واضح کرتا ہے کہ لوگوں کی ان خواہشات کی پیروی سے منع کیا گیا ہے جو حق یعنی وحی الٰہی سے متصادم ہوں۔ اس کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا یہ ارشاد گرامی سامنے رکھ لیں جو بخاری شریف میں حضرت ابوہریرہ سے روایت ہوا ہے کہ: ”بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام علیہم السلام کرتے تھے، ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے میرے بعد خلفاء ہوں گے۔”
گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں وحی الٰہی کی بنیاد پر انبیائے کرام علیہم السلام کے ذریعے چلنے والے حکومتی نظام کا تسلسل اب بھی قائم ہے، البتہ اب چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے یہ تسلسل اب خلفاء کے ذریعے آگے بڑھے گا اور یہی اسلام کا نظام خلافت ہے۔ (جاری ہے)